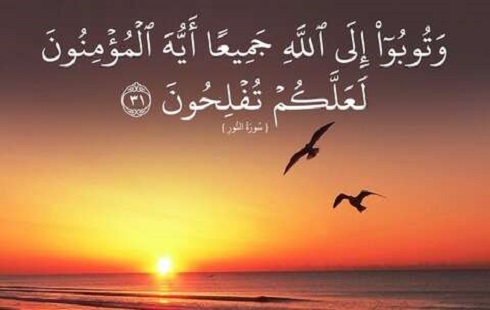فضائل امام محمد تقی علیہ السلام
محمد بن علی بن موسی (195–220 ھ) امام محمد تقی ؑ کے نام سے مشہور شیعوں کے نویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے۔ آپ نے 17 سال امامت کے فرائض انجام دیئے اور 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ شیعہ آئمہ میں آپ سب سے کم عمر شہید امام ہیں۔بچپن میں امامت ملنے کی وجہ سے امام رضاؑ کے بعض اصحاب نے ان کی امامت میں تردید کی جس کے نتیجے میں عبدالله بن موسی کو امام کہنے لگے اور کچھ دیگر افراد نے واقفیہ کی بنیاد ڈالی لیکن اکثر اصحاب نے آپ کی امامت کو قبول کیا۔امام محمد تقیؑ کا لوگوں کے ساتھ ارتباط وکالتی سسٹم کے تحت خط و کتابت کے ذریعے رہتا۔ آپ کے زمانے میں اہل حدیث، زیدیہ، واقفیہ اور غلات جیسے فرق بہت سرگرم تھے اسی بنا پر آپ شیعوں کو ان کے باطل عقائد سے آگاہ کرتے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتے اور غالیوں پر لعن کرتے تھے۔دوسرے مکاتب فکر کے علماء و دانشوروں کے ساتھ مختلف کلامی اور فقہی موضوعات پر آپ کے علمی مناظرے ہوئے جن میں شیخین کی حیثیت، چور کے ہاتھ کاٹنے اور احکام حج کے بارے میں مناظرہ، آپ کے معروف مناظرے ہیں۔
نام و نسب
امام محمد تقی علیہ السلام آسمان عصمت کے گیارهویں درخشاں ستارے اور ہمارے نویں امام ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی رضاعلیہ السلام اور والدۀ ماجدہ حضرت سبیکہ علیھا السلام ہیں جن کا تعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلّم کی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنها سے ہے۔ آپ کی والدہ کے ناموں میں "ریحانہ" اور "خیزران" بھی شامل ہیں۔ آپ فضائل و کمالات کے اعتبار سے اپنے زمانہ کی بلند مرتبہ خاتون تھیں ۔ (۱)یہاں تک کہ خود امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی زبان عصمت سے انہیں با فضیلت اور پاکدامن خاتون کہا ہے۔(۲)
امام کے دو بیٹے تھے:
۱- امام علی نقی علیہ السلام جو ہمارے دسویں امام ہیں۔
۲- حضرت موسیٰ مبرقع علیہ السلام جن سے رضوی سادات کی نسل چلی جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہے۔
شیخ مفید کی روایت کے مطابق امام محمد تقی کی چار اولاد امام علی نقی، موسی مبرقع، فاطمہ و اَمامہ ہیں۔(3) البتہ بعض راویوں نے آپؑ کی بیٹیوں کی تعداد حکیمہ، خدیجہ و ام کلثوم کے نام سے تین بتائی ہے۔(4)
القاب اور کنیت
جواد، تقی، مرتضی، قانع، رضی، مختار، باب المراد وغیرہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ اور "ابو جعفر "آپ کی کنیت ہے۔ چونکہ آپ کی کنیت اور پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ایک جیسی ہے لہذا فرق کے لئے آپ کی کنیت کے آگے "ثانی" کا اضافہ کر تے ہوئے "ابو جعفر ثانی" لکھا جاتا ہے۔
ولادت
امام محمد تقی علیہ السلام ۱۰ رجب المرجب ۱۹۵ھ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام نے پہلے ہی امام کی ولادت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی ہمشیرہ جناب حکیمہ علیها السلام سے فرمایا: آج خیزران کا بابرکت بیٹا دنیا میں آئے گا لہذا اب سات دن تک ان کے ساتھ رہيے گا۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں: جب امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک ایسا نور ساطع ہوا جس سے پورا حجرہ روشن ہوگیا ۔(5) دنیا میں آنے کے بعد آپ کی زبان اقدس پر یہ جملے جاري ہوئے:" أشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلّا اللّه وَاَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّه"۔ ولادت کے تیسرے روز جب آپ کو چھینک آئی تو فرمایا:" اَلْحَمْدُ للّه وَصَلّی اللّه عَلی مُحَمَّدٍ وَعَلَی الأئِمّة الرّاشِدین "۔ جناب حکیمہ نے جب امام محمد تقی علیہ السلام کے لب مبارک سے یہ جملے سنے تو آپ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا: میں اس بچے میں عجیب و غریب اور حیرت انگیز چیزوں کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ امام نے فرمایا:"یا حَکیمةُ، ماتَرَوْنَ مِنْ عَجائِبِه أَکْثَرُ "۔ اے حکیمہ! آئندہ مزید حیرت انگیز باتوں کا مشاہدہ کیجئے گا۔(6)
امام محمد تقی علیہ السلام، اس زمانے مین بابرکت مولود اور خوش قدم بچہ کے عنوان سے مشہور تھے، جس کا اصل سبب امام علی رضا علیہ السلام کا وہ ارشاد تھا جسے ابو یحیی صنعانی نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ایک روز میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اسی دوران آپ کے فرزند ابو جعفر کو لایا گیا جو ابھی بہت چھوٹے تھے، امام نے فرمایا: اس نو مولود بچہ سے زیادہ ہمارے شیعوں کے لئےباعث برکت کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ مکہ میں بھی کچھ لوگوں کے درمیان آپ نے یہی فرمایا ۔(7)(8)
عصر امامت
امام تقریبا سات برس اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ رہے۔ اس کمسنی میں آپ کو اپنے بابا کی مظلومانہ شہادت سے روبرو ہونا پڑا۔ اپنے بابا کی جانگداز شہادت کے بعد آپ امامت کے ظاہری منصب پر فائز ہوئے ۔ اتنی کمسنی میں منصب امامت کی باگ ڈور سنبھالنے والے آپ واحد امام ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا تھا جس کے موجب آٹھویں امام کے بعض صحابہ تک شک و تردید میں مبتلا ہوگئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام علی رضا اور خود امام محمد تقی علیهما السلام نے اس سلسلہ میں روشنی ڈالی اور شبهات کا جواب دیا۔ خالص اسلامی اور شیعی عقیدہ کی بنیاد پر امامت میں سن اور عمر کی شرط نہیں ہوتی۔ امامت بھی نبوت کی طرح الہی عہدہ ہے لہذا اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جس عمر میں چاہے ، اپنے عہدے، مورد نظر بندوں کے سپرد کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں:
1- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب آپ ماں کی گود میں ہوا کرتے تھے اس وقت فرمایا: ۔ "میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اورمجھے نبی قرار دیا ہے"۔(9)
2- حضرت یحیی علیہ السلام کے سلسلہ میں بھی صاف طور پر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا کی۔ ارشاد ہوتا ہے: "ہم نے انہیں [یحیی] کو بچپنے میں منصب نبوت عطا کیا"۔(10)
لہذا جس طرح اللہ نے حضرت عیسی اور حضرت یحیی علیهما السلام کو بچپنے میں نبی بنایا اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام کو بچپنے میں امام بنایا۔ اگر چہ نویں امام کافی کم عمری میں ظاہری منصب امامت پر فائز ہوئے تاہم آپ کی امامت کا سترہ برس پر مشتمل دور بہت سے دیگر معصومین علیهم السلام کی مدّت امامت سے قدرے طولانی ہے۔ مامون اور معتصم آپ کے ہمعصر عباسی خلفاء تھے۔
امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون خراسان سے بغداد گیا ۔ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے علمی و معنوی فضائل سے خوب آگاہ تھا لہذا اس نے امام کو مدینہ سے بغداد آنے کی دعوت دی۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ امام کی فعالیتوں پر نظر رکھ سکے ۔ وہ امام کی شادی اپنی بیٹی ام الفضل سے کرنا چاہتا تھا، یہ چال بھی اس کے اس مقصد کا ہی حصہ تھی، اس کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اپنے خلاف اٹھنے والی علوی تحریکوں کو خاموش کر سکے۔ اس کے قریبیوں کو اس شادی پر اعتراض تھا لہذا اس نے ایک مناظراتی نشست منعقد کروائی جس میں امام نے مختلف علماء و دانشوروں کے سوالات کے جوابات دئے ، سب کے سب مبہوت ہوکر رہ گئے۔ اس کے بعد مامون نے اپنی بیٹی کی شادی امام سے کردی۔
ظاہر ہے یہ شادی امام کی رضایت پر مبتنی نہ تھی بلکہ مامون نے امام کو اس بات پر مجبور کیا تھا ،یہاں تک کہ انہیں قتل کی دھمکی تک دی تھی۔ اگرچہ امام کی لغت زندگی میں خوف نام کا کوئی لفظ نہیں ہوتا لیکن کبھی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں شہادت سے زیادہ امام کے زندہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصلحت خدا یہی تھی کہ امام زندہ رہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر امام شادی نہ کرتے تو آپ کو تو شہید کیا ہی جاتا، شیعوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ ہمارے معصومین علیهم السلام کا ہمیشہ ایک اہم مقصد شیعوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ مامون کی بیٹی سے شادی کی صورت میں، شیعوں کے خلاف اس کی سازشوں میں قدرے کمی آ سکتی تھی جو کہ آئی بھی۔
امام محمد تقی علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت سمانہ علیها السلام تھیں۔ آپ دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی والدۀ ماجدہ ہیں۔ آپ نہایت عفیف اور با فضیلت خاتون تھیں۔
امام کےعلم و اخلاق کے چند نمونے
امام محمد تقی علیہ السلام اعلیٰ اخلاقی فضائل و کمالات کے حامل تھے۔ بے مثال زہد و تقویٰ، عبادت و بندگی،علم و حلم،حسن خلق، جود و سخا، عفو و درگذر جیسی دیگر تمام خصوصیات آپ کے کردار کی آئینہ دار نظر آتی ہیں۔ آپ کی عظمت و فضیلت کا اظہار و اعتراف علمائے شیعہ ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے بھی کیا ہے:
ابن جوزی کہتے ہیں: "آپ علم و تقویٰ اور زہد و بخشش میں اپنے پدر بزرگوار کے راستہ پر تھے"۔(11)
ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں: "…آپ کمسنی میں ہی علم و دانش اور حلم و بردباری میں تمام دیگر دانشوروں پر برتری رکھتے تھے"۔(۱2)
شبلنجی کہتے ہیں: "… آپ نے کمسنی میں ہی اپنے فضل و علم اور کمال عقل کا مظاہرہ کیا اور اپنے برہان کو لوگوں پر واضح کر دیا"۔(13)
آپ کی ذات ستودہ صفات پر بطور کامل روشنی ڈالنا اور آپ کے تمام کمالات کو شمار کرنا یقیناً نا ممکن ہے، بس نمونہ کے طور پر چند مثالیں معروض ذیل ہیں:
علم و دانش
امام جواد علیہ السلام علم کے میدان میں سرآمد روزگار تھے۔ آپ کا وجود علوم الہیہ کا مخزن تھا ۔ آپ خدا داد علمی صلاحیتوں کے ایسے مالک تھے کہ انتہائی کمسنی میں آپ نے زمانے کے بڑے بڑے عالموں سے مناظرہ کیا اور انہیں اپنے مستحکم دلائل و برہان کے ذریعہ مبہوت و لاجواب کر دیا۔ جن میں سر فہرست یحیی بن اکثم کے ساتھ ہونے والا مناظرہ ہے جسے تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ۔ (۱4)خود مامون کو اعتراف کرنا پڑا:"اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کے لئے کمسنی ، عقل کے کمال میں رکاوٹ نہیں ہوتی "۔ (۱5)دوست و دشمن آپ کےبے نظیر علم و فضل کے قائل تھے۔ بڑے بڑے راوی، محدثین، فقہاء و علماء نے اس کمسن امام کے حضور زانوئے ادب تہہ کئے اور اس منبع علوم سے فیضیاب ہوئے۔ علمی آثار و مکتوبات پر تاریخ کی بے انتہا جفاکاریوں کے باوجود،موجودہ کتب احادیث و تفاسیر میں عقائد، تفسیر، فقہ اور دیگر موضوعات کے سلسلہ میں آپ سے بکثرت روایات نقل ہوئی ہیں۔
على بن مهزيار، محمد بن ابى عمير، احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، زكريا بن آدم، محمد بن اسماعيل،فضل بن شاذان، حضرت عبد العظیم حسنی، حبيب بن اوس طائى، حسن بن محبوب، على بن اسباط، عبدالله بن الصلت، سعد بن سعد القمى، حسن بن سعيد اهوازى، دعبل خزاعی جیسی بہت سی دیگر عظیم ہستیوں کو آپ کی شاگردی کا شرف و افتخار حاصل ہے۔
یحیی بن اکثم کے ساتھ ہونے والا مناظرہ
ایک روز خلیفہ کی موجودگی میں جب امام جوادؑ، یحیي بن اکثم اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یحیي نے امام علیہ السلام سے کہا :روایت ہوئی ہے کہ جبرئیلؑ،پیغمبر اکرم(ص) کی خدمت میں پہنچے اور کہا : یا محمدؐ ! خداوند عالم نے آپ پر سلام کہا ہے اور کہا ہے : میں ابوبکر سے راضی ہوں، اس سے پوچھو کہ کیا وہ بھی مجھ سے راضی ہے؟ اس حدیث کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟
امامؑ نے فرمایا: جس راوی نے یہ خبر نقل کی ہے اس کو دوسری وہ خبر بھی بیان کرنی چاہئے تھی جو پیغمبرؐ اکرم نے حجة الوداع میں بیان کی تھی، پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا تھا : جو بھی میرے اوپر جھوٹی تہمت لگائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لہذا اگر میری کوئی حدیث تمھارے سامنے پیش کی جائے تو اس کو کتاب خدا اور میری سنّت سے ملا کر دیکھو، جو بھی کتاب خدا اور میری سنّت کے مطابق ہو اس کو لے لو اور جو کچھ کتاب خدا اور میری سنت کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو ۔
امام محمد تقی (علیہ السلام) نے مزید فرمایا: (ابوبکر کے متعلق) یہ روایت خدا کی کتاب سے موافقت نہیں رکھتی کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا ہے : ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے اور ہم اپنے بندے سے اس کی شہ رگ سے زیادہ نزدیک ہیں (سوره ق: 16)۔ کیا ابوبکر کی خوشنودی یا ناراضگی خدا کے لیے پوشیدہ تھی کہ وہ اس کے بارے میں پیغمبر اکرم (ص) سے پوچھتا؟ یہ بات عقلی طور پر محال ہے۔
یحیی نے کہا: اس طرح بھی روایت ہوئی ہے : ابوبکر اور عمر زمین پر اس طرح ہیں جیسے آسمان پر جبرئیلؑ و میکائیلؑ ہیں ۔
آپؑ نے فرمایا: اس حدیث کے متعلق بھی غور و فکر سے کام لو۔ جبرئیلؑ و میکائیلؑ خداوندعالم کی بارگاہ میں مقرب دو فرشتے ہیں اور ان دونوں سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے اور یہ دونوں ایک لمحہ کے لئے بھی خدا کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہیں ہوئے ہیں جبکہ ابوبکر اور عمر ایک عرصے تک مشرک تھے اگرچہ ظہور اسلام کے بعد مسلمان کہلائے مگر ان کی بیشتر عمر حالت شرک اور بت پرستی میں گزری ہے۔ اس بناء پر محال ہے کہ خداوند عالم ان دونوں کو جبرئیلؑ اور میکائیلؑ سے تشبیہ دے ۔
یحیی نے کہا: اسی طرح ایک اور روایت ہوئی ہے کہ ابوبکر اور عمر اہل بہشت میں بوڑھے لوگوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟
آپؑ نے فرمایا: اس روایت کا صحیح ہونا بھی محال ہے کیونکہ تمام اہل بہشت جوان ہوں گے اوران کے درمیان کوئی ایک بھی بوڑھا نہیں ہوگا(تاکہ ابوبکر اور عمر ان کے سردار بن سکیں) یہ روایت بنی امیہ نے پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی اس حدیث کے مقابلے میں کھڑی کی ہے جو امام حسن اور امام حسین (علیہما السلام ) کے متعلق بیان ہوئی ہے ،نقل ہوا ہے کہ حسنؑ و حسینؑ، جوانان جنت کے سردار ہیں ۔
یحیی نے کہا: یہ بھی ایک روایت نقل ہوتی ہے کہ “عمر بن خطاب اہل بہشت کے چراغ ہیں۔”
آپؑ نے فرمایا: یہ بھی محال ہے کیونکہ بہشت میں خدا کے مقرب فرشتے، انبیاء، جناب آدم، آنحضرتؐ اور تمام فرشتے موجود ہیں پھر کس طرح ممکن ہے کہ بہشت ان کے نور سے روشن نہ ہو لیکن عمر کے نور سے روشن ہوجائے؟
یحیی نے کہا: روایت ہوئی ہے کہ “سکینہ” عمر کی زبان سے بولی ہوئى باتیں ہیں۔ (یعنی عمر جو کچھ کہتے ہیں وہ ملائکہ اور فرشتوں کی طرف سے ہے) ۔
آپؑ نے فرمایا: ۔۔۔ ابوبکر جو کہ عمر سے افضل تھے، منبر کے اوپر کہتے تھے: میرے پاس ایک شیطان ہے جو مجھے منحرف کردیتا ہے، لہذا تم جب بھی مجھے منحرف ہوتے ہوئے دیکھو تو میرا ہاتھ پکڑ لینا ۔
یحیی نے کہا: یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے فرمایا: اگر میں نبوت کے لئے مبعوث نہ ہوتا تو یقیناً عمر مبعوث ہوتے ۔
آپؑ نے فرمایا: یقیناً کتاب خدا (قرآن کریم) اس حدیث سے زیادہ سچی اور صحیح ہے، خداوند عالم نے اپنی کتاب میں فرماتا ہے : (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) ( سورہ احزاب، آیت ٧) ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیاء( علیہم السّلام) سے اور بالخصوص آپؐ سے اور نوح (علیہ السلام)،ابراہیم (علیہ السّلام)، موسیٰ (علیہ السّلام) اور عیسٰی بن مریم (علیہما السلام) سے عہد لیا اور سب سے بہت سخت قسم کا عہد لیا۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا تھا پھر کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو بدل دیتا؟ انبیاء میں سے کسی ایک نبی نے ذرا سی دیر کے لئے بھی شرک اختیار نہیں کیا، لہذا کس طرح ممکن ہے کہ خداوند عالم ایسے شخص کو نبوت کے لئے مبعوث کرے جس کی عمر کا اکثر و بیشتر حصہ خدا کے شرک میں گزرا ہو؟ نیز پیغمبر اکرم (ص) نے فرمایا : جس وقت آدمؑ آب و گل کے درمیان تھے (یعنی ابھی خلق نہیں ہوئے تھے) میں اس وقت بھی نبی تھا ۔
یحیی نے پھر کہا: روایت ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے فرمایا : کبھی بھی مجھ سے وحی قطع نہیں ہوئی اور اگر قطع ہوئی تو مجھے یہ خیال آیا کہ وحی خطاب (عمر کے باپ) کے گھر میں منتقل ہوگئی ہے ۔ یعنی نبوت میرے گھر سے ان کے گھر میں منتقل ہوگئی ہے ۔
آپؑ نے فرمایا: یہ بھی محال ہے کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبرؐ اکرم اپنی نبوت میں شک کریں، خداوند عالم فرماتا ہے: خداوند فرشتوں اور اسی طرح انسانوں کے درمیان سے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے( سوره حج: 75) ۔ اس بناء پر خدا کے انتخاب کے بعد پیغمبر اکرم (ص) کے لئے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا) ۔
یحیی نے کہا: روایت میں ذکر ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے فرمایا: اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر کے علاوہ کسی اور کو نجات نہ ملتی ۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ بھی محال ہے کیونکہ خداوند عالم نے پیغمبر اکرم (ص) سے فرمایا ہے : جب تک تم ان کے درمیان ہو اس وقت تک خداوند عالم ان پر عذاب نہیں کرے گا اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک ان پر عذاب نہیں ہوگا (سوره انفال: 33) ۔ اس وجہ سے جب تک پیغمبر اکرم (ص) ان کے درمیان ہیں اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا.(16)
احکام حج کے بارے میں مناظرہ
یحیی ابن اکثم نے امام تقى عليه السلام سے پوچھا: کیا اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟
امام محمد تقی (ع)نے اس سے سوال کیا: اس نے شکار حرم میں کیا تھا یا حرم کے باہر، محرم عالم تھا یا جاہل، عمداً ایسا کیا تھا یا غلطی سے ایسا ہوگیا تھا، محرم آزاد تھا یا غلام، وہ عمرہ کے احرام میں تھا یا حج کے احرام میں؟
یحیی ابن اکثم ان سوالات کا جواب دینے سے حیران رہ گیا اس طرح کہ اس کے چہرہ پر عاجزی کے آثار نمایاں ہوگئے اور حاضرین نے اچھی طرح اسے محسوس کر لیا۔ اس وقت مامون نے کہا اس نعمت اور توفیق پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھا اور کہا دیکھا تم نے میں نے جو کچھ ابو جعفر(ع) کے بارے میں کہا تھا وہ حق تھا۔
پھر اس کے بعد امام تقى(ع)سے عرض کیا اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان فقہی مسائل کی فروعات کا جواب آپ خود ہی دیدیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہوسکے۔
امام(ع)نے فرمایا: اگر شکار حرم کے باہر کیا ہو اور وہ شکار بڑے پرندے کا ہو تو ایک گوسفند کفارہ میں دے۔
اگر حرم میں مارا ہو تو دو گوسفند دے۔
اگر شکار جوجہ (چھوٹے پرندہ) کا ہو اور حرم کے باہر مارا ہو تو ایک گوسفند کا بچہ کفارے میں دے جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔
اور اگر جنگلی گدھے کا شکار کیا ہو تو اس کا کفارہ ایک گائے ہے ۔
اگر شتر مرغ کا شکار کیا ہو تو اس کا کفارہ ایک اونٹ ذبح کرنا ہے۔
اگر شکار ہرن کا ہو تو اس کا کفارہ ایک گوسفند ہے۔
اگر ان میں سے کسی ایک کا شکار حرم میں کیا ہو تو کفارہ دو گنا ہوجائے گا اور کعبہ کے پاس ذبح کرنا پڑے گا۔
اگر احرام حج کا ہو تو وہ قربانی کا جانور ساتھ لیکر آئے اور اسے منی میں ذبح کرے حالت احرام میں کفارہ عالم اور جاہل دونوں کے لئے برابر ہے.
اگر عمداً کیا ہو تو گناہگار بھی اور اگر غلطی سے ہوگیا ہو تو گناہگار نہ ہوگا صرف کفارہ واجب ہوگا۔
جو کفارہ آزاد شخص پر واجب ہے وہ خود اسے دینا پڑے گا لیکن اگر غلام ہے تو اس کا کفارہ اس کے آقا پر لازم ہے۔
اگر شکار کرنے والا نابالغ ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنے والا اگر اپنے عمل پر توبہ کرلے تو آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا لیکن اگر توبہ نہ کرے اور اپنے گناہ پر اصرار کرے تو آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔
یہ سن کر مامون نے کہا: شاباش ابو جعفر خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے اگر مناسب سمجھیں تو آپ بھی یحیی سے کوئی سوال کریں۔
ايك عورت كى طرف نظر كرنا حلال اور حرام
امام ابو جعفر(ع)نے یحیی ابن اکثم سے فرمایا: اجازت ہے کہ ایک سوال کروں؟
اس نے عرض کیا: پوچھئے اگر مجھے اس کا جواب معلوم ہوا تو جواب دے دوں گا ورنہ اس کا جواب خود آپ ہی سے معلوم کرلوں گا۔
امام(ع)نے فرمایا: مجھے ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جس نے دن کی ابتدا میں ایک عورت کی طرف دیکھا تواس کا دیکھنا حرام تھا، دن چڑھ جانے کے بعد اس مرد کے لئے اس عورت کی طرف دیکھنا حلال ہوگیا۔ ظہر کے وقت اس عورت کی طرف دیکھنا پھر حرام ہوگیا اور عصر کے وقت اس کی طرف دیکھنا حلال ہوگیا، غروب آفتاب کے بعد دوبارہ اس عورت پر نظر ڈالنا حرام ہوگیا، عشاء کے وقت پھر حلال ہوگیا، آدھی رات میں پھر حرام ہوگیا، طلوع فجر کے وقت پھر حلال ہوگیا۔ یہ عورت کیسی عورت ہے اور یہ حلیت و حرمت کس طرح پیش آتی ہے؟
یحیی ابن اکثم نے عرض کیا: مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں معلوم، آپ بتا دیجئے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔
امام(ع)نے فرمایا: مذکورہ عورت ایک کنیز ہے جس کی طرف دن کی ابتدا میں ایک نامحرم دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا حرام ہے لیکن دن چڑھے وہ مرد اس کنیز کو اس کے آقا سے خرید لیتا ہے تو اس کی طرف دیکھنا حلال ہو جاتا ہے۔ ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیتا ہے تواس کی طرف دیکھنا پھر حرام ہو جاتا ہے۔ عصر کے وقت اس سے شادی کرلیتا ہے اوراس عورت کو دیکھنا حلال ہو جاتا ہے ۔مغرب کے وقت ظہار کی صورت میں اس سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ عشاء کے وقت کفارہ دیدیتا ہے اور اس کی طرف دیکھنا پھر حلال ہو جاتا ہے۔ آدھی رات میں اسے طلاق دیدیتا ہے اوراس کی طرف دیکھنا حرام ہو جاتا ہے ۔ طلوع فجر کے وقت اسے پھر رجوع کر لیتا ہے اور اس کی طرف دیکھنا حلال ہو جاتا ہے۔
یہ سن کر مامون نے حاضرین کی طرف رخ کر کے کہا: تم میں سے کون اس طرح فقہی مسائل کا جواب دے سکتا ہے؟
ان لوگوں نے عرض کیا: ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے۔
مامون نے کہا: تم لوگوں نے جو فضل و کمال اور جو علم دیکھا وہ اہلبیت(ع)کا خاصہ ہے اور کمسنی ان کو ان کمالات سے محروم نہیں کرتی ہے۔
جب حاضرین امام جواد(ع)کے فضائل و کمالات سے آگاہ ہوگئے تو مامون نے امام(ع)کے ساتھ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کر دیا۔خطبۂ عقد پڑھا گیا اور حاضرین کے درمیان ہدایا تقسیم کئے گئے۔ (17)
جود و کرم
امام علی رضا علیہ السلام نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: مرکزی دروازہ سے رفت و آمد کیا کیجئے۔ اپنے ساتھ سونے چاندی رکھا کیجئے اور اپنے چچا حضرات کو ۵۰ دینار سے کم نہ دیا کیجئے، انفاق کیجئے اور فقر و تنگدستی کا خوف نہ رکھئے اس لئے کہ اللہ کی قدرت آپ کے ساتھ ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے بابا کی نصیحت پر ہی عمل کیا کرتے تھے۔(۱8)
لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ائمہ معصومین علیهم السلام کی زندگی کا اہم جزو ہے۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام بھی اس میدان میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کسی ضرورتمند کے ساتھ نیکی کرناجتنا اس ضرورتمند انسان کے لئے مفید ہے اس سے زیادہ خود نیکی کرنے والے کے لئے فائدہ مند ہے۔ آپ فرماتے ہیں: نیکی کرنے والوں کو نیکی کرنے کی ضرورت محتاجوں اور ضرورتمند انسانوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعہ نیک افراد اپنے پروانۀ اعمال میں جزائے آخرت اور نیک نامی و افتخار کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو بھی محتاجوں کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے درحقیقت وہ پہلے اپنے حق میں نیکی کرتا ہے، لہذا اسے ایسے عمل کے شکریہ اور قدردانی کی توقع دوسرے سے نہیں رکھنا چاہئے جسے اس نے اپنے لئے انجام دیا ہے۔(۱9)
عقدہ کشائی
روایت میں آیا ہے کہ خراسان کے سجستان کا ایک شخص سفر حج کے دوران امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں اپنے شہر کے گورنر کا مقروض ہوں، وہ آپ اہل بیت کا دوستدار ہے، آپ ایک مکتوب اس کے نام تحریر کردیجئے تاکہ میرا ٹیکس معاف کر دے۔ امام نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس پر تحریر فرمایا: "نامہ بر کا کہنا ہے کہ تم خوش عقیدہ انسان ہو ، لہذا اس کے ساتھ نیکی کرو" ۔ والی شہر حسين بن عبدالله نيشابورى کو خط کے بارے میں پہلے ہی خبر ہو گئی تھی لہذا وہ سجستان میں اس کے استقبال کو پہنچا، اس کی مشکلات کو جانا، ٹیکس معاف کیا اور اس کی مناسب مدد بھی کی۔(20)
صبر و بردباری
نویں امام مصائب و آلام کے مقابلہ میں انتہائی صبر کرنے والے تھے۔ آپ کبھی مضطرب نہیں ہوتے تھے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حلم و بردباری کی راہ پر باقی رہتے تھے۔ بد اخلاق اور کج دہن زوجہ کے مقابلہ میں صبر و بردباری، ظالم و جابر حاکموں کے مقابلہ میں اللہ پر بھروسہ اور اپنے بابا کی شہادت جیسے دردناک واقعات پر تحمّل کا مظاہرہ، آپ کی اس عظیم صفت کی چند مثالیں ہیں۔ آپ صبر و شکیبائی کو نیک انسانوں کی ایک اہم صفت جانتے تھے۔(21)
استجابت دعا
داؤد بن قاسم کہتے ہیں: "ایک دن میں امام جوادؑ کے ہمراہ ایک باغ میں پہنچا اور میں نے عرض کیا: "میں آپ پر فدا ہوجاؤں! میں مٹی اور گارا کھانے کا بہت شوقین ہوں؛ آپ دعا فرمائیں (تاکہ میں اس عادت سے چھٹکارا پاؤں)۔ آنجناب نے جواب نہیں دیا اور چند روز بعد بغیر کسی تمہید کے فرمایا: "اے ابا ہاشم! خداوند متعال نے مٹی کھانے کی عادت تم سے دور کردی”۔ ابو ہاشم کہتے ہیں: اس دن کے بعد میرے نزدیک مٹی کھانے سے زیادہ منفور چیز کوئی نہ تھی”۔(22)
درخت پر پھل آ جانا
بغداد سے مدینہ واپسی کے وقت بڑی تعداد میں لوگ امام جوادؑ کو وداع کرنے کے لئے شہر سے باہر تک آئے۔ نماز مغرب کے وقت ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک پرانی مسجد تھی۔ امامؑ نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد کے صحن میں سدر (بیری) کا ایک درخت تھا جس نے اس وقت تک پھل نہیں دیا تھا۔ امامؑ نے پانی منگوایا اور درخت کے پاس بیٹھ کر وضو کیا اور نماز جماعت ادا کی اور نماز کے بعد سجدہ شکر بجالائے اور بعدازاں بغدادیوں سے وداع کرکے مدینہ روانہ ہوئے۔ اس رات کے دوسرے روز اس درخت نے خوب پھل دیا؛ لوگ بہت حیرت زدہ ہوئے۔ مرحوم شیخ مفید کہتے ہیں: "میں نے برسوں بعد اس درخت کو دیکھا اور اس کا پھل کھایا۔(23)
شہادت
عباسی خلیفہ معتصم نے امام جوادؑ کو مدینے سے بغداد بلوایا۔ امامؑ 28 محرم الحرام سنہ 220 ہجری کو بغداد پہنچے اور اسی سال ذی قعدہ کے مہینے اسی شہر میں وفات پاگئے۔(24) بعض مآخذ میں ہے کہ آپ پانچ یا چھ ذی الحج کو وفات پاگئے(25) اور بعض مآخذ میں کہا گیا ہے کہ آپؑ ذوالقعدہ کی آخری تاریخ کو شہادت پاگئے۔(26)
آپؑ کی شہادت کے اسباب کے حوالے سے، مروی ہے کہ بغداد کے قاضی ابن ابی داؤد نے معتصم عباسی کے ہاں چغل خوری کی اور اس سخن چینی کا اصل سبب یہ تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں امامؑ کی رائے پر عمل ہوا تھا اور یہ بات ابن ابی داؤد اور دیگر درباری فقہاء کی شرمندگی کا باعث ہوئی تھی۔ بہر حال ابن ابی داؤد نے بادشاہ کو شیشی میں اتار دیا تو اس نے قتل امامؑ کا ارادہ کیا جبکہ آپؑ کی عمر 25 سال سے زیادہ نہ تھی۔ معتصم نے اپنی اس نیت کو اپنے ایک وزیر کے توسط سے عملی جامہ پہنایا جس نے امامؑ کو زہر دے کر شہید کردیا۔(27) البتہ بعض دوسروں کی رائے ہے کہ امامؑ کو ام الفضل بنت مامون نے زہر دیا تھا۔(28)
شیخ مفید (متوفی 413 ہجری) کہتے ہیں: "اگرچہ بعض لوگوں کی رائے کے مطابق امامؑ کو زہر کھلا کر شہید کئے گئے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے چنانچہ میں اس سلسلے میں گواہی نہیں دے سکتا”(29)۔ تاہم مسعودی (متوفی 346ہجری) کا کہنا ہے کہ: "معتصم عباسی اور ام الفضل کا بھائی جعفر بن مامون مسلسل امامؑ کو زہر دینے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ چونکہ ام الفضل کی کوئی اولاد نہ تھی اور امام ہادیؑ امام جوادؑ کی دوسری زوجہ سے تھے۔ جعفر نے اپنی بہن کو اکسایا کہ آپؑ کو زہر دے کر قتل کرے۔ چنانچہ اس نے زہر انگور کے ذریعے امامؑ کو کھلا دیا۔ مسعودی کے بقول ام الفضل امام کو زہر دینے کے بعد پشیمان ہوئی اور رورہی تھی۔ اسی حال میں امامؑ نے اس کو بد دعا دی اور آپؑ کی شہادت کے بعد ام الفضل بہت شدید مرض میں مبتلا ہوئی۔(30)
حواله جات
۱ ۔ اثبات الوصیۃ ، مسعودی ص ۲۰۹
۲۔ بحار الانوار، علامہ مجلسی، ج۵۰ ص۱۵۰
3۔ الارشاد، مفید، ج2، ص284
4۔ مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب، ج 4،ص 380۔
5۔ منتهی الامال، ج۱، ص۲۱۸
6۔ اعلام الهدایه، ص۲۸
7۔ اصول کافی، ج۱، ص۳۲۱؛ الارشاد، شیخ مفید، ص۳۱۹؛ اعلام الوری، طبرسی، ص۳۴۷؛ کشف الغمه، اربلی، ج۳، ص۱۴۳
8۔ فروع کافی، دارالکتب الاسلامیه، ج۶، ص۳۶۱؛ الامام الجواد من المهد الی اللحد، سیدکاظم قزوینی، مؤسسه البلاغ، ص۳۳۷ 9۔ سورہ مریم/۳۱
10۔ سورہ مریم/۱۲
11۔ تذکره الخواص، ص ۳۵۹
۱2۔ الصواعق المحرقه، ص ۲۰۵
۱3۔ نور الابصار، ص ۱۶۱
۱4۔ بحار الأنوار، علامہ مجلسی،ج 50، ص 75 - 76
۱5۔ اعلام الوری، فضل بن حسن طبرسی، ص۳۵۳
16۔ احتجاج، علامہ طبرسى، ج 2، ص 247 – 248 ، بحار الأنوار، علامہ مجلسى، ج 50، ص 80 – 83
17۔ الارشاد، ج۲، ص۲۸۱؛ الفصول المہمہ، ص۲۴۹
۱8۔ کافی، شیخ کلینی، ج۴، ص۴۳
۱9۔ اربلی، کشف الغمۃ،ص۱۹۲
20۔ کافی، شیخ کلینی، ج۵، ص ۱۱۱
21۔ اربلی، کشف الغمۃ،ج۳، ص۱۹۵
22۔ الارشاد، شیخ مفید، ج2، ص586
23۔مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب، ج4، ص390، الارشاد، شیخ مفید، ج2، ص278، فتال نیشابوری، ص241و242
24۔ الارشاد، مفید، ص481
25۔ ابنابیالثلج، ص13
26۔ سعد بن عبدالله اشعری؛ ص99۔ فضل بن حسن طبرسی، 1417، ج2، ص106
27۔ تفسیر، عیاشی، ج1، ص320
28۔ زندگانی سیاسی امام جواد، عاملی، ص153
29۔الارشاد، شیخ مفید، 2/311
30۔ اثبات الوصیۃ للامام علی بن ابی طالب علیہ السلام، المسعودی، ص192